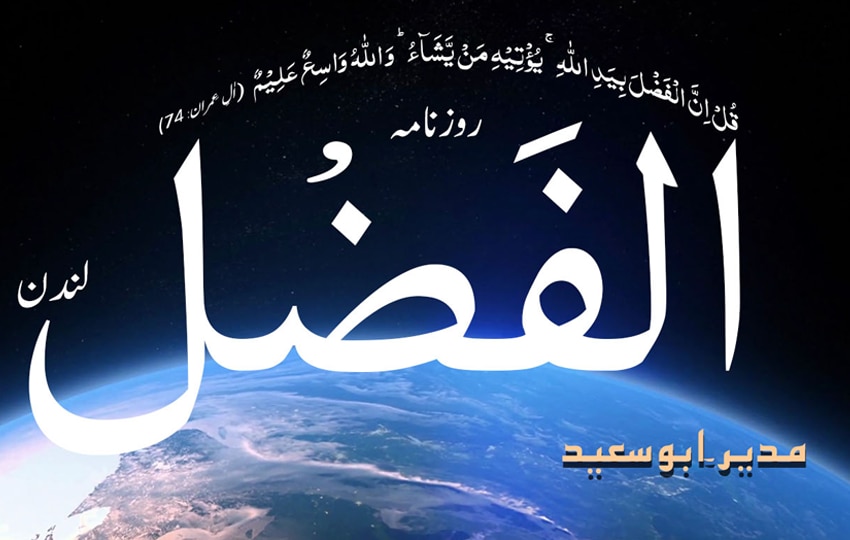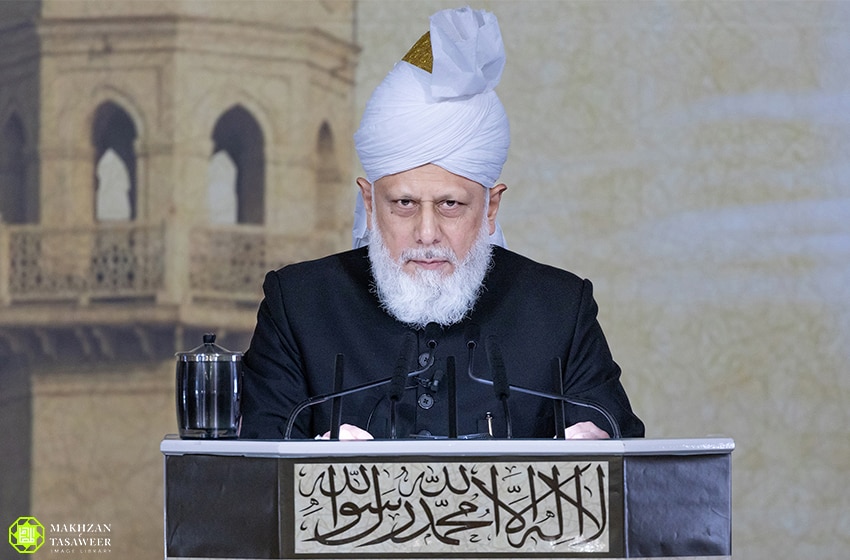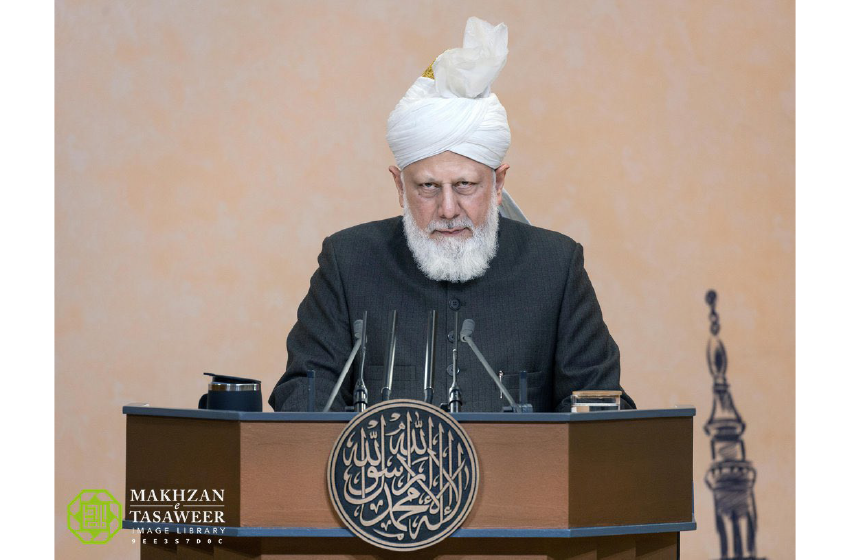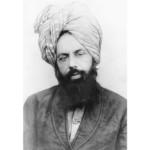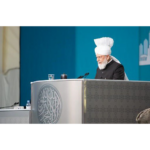جب کوئی زبان اپنی نشوونما کی ابتدائی منازل عبور کر کے اس حد بلوغت تک پہنچ جاتی ہے کہ اسے تخلیقی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاسکے تو ارباب ذوق خالقین ادب اس زبان کے خد و خال اور حسن و جمال، معیار لسان، فصاحت اور بلاغت کو مزید نکھارنے اور سنوارنے کے لیے ارادی اور غیرارادی، اجتماعی اور بسا اوقات انفرادی سطح پر زبان و بیان کی اصلاح کا آغاز کرتے ہیں۔
اس اصلاح کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ بعض الفاظ اور تراکیب کو تخلیقی مقاصد کے لیے ناکارہ قرار دے کر ترک کر دیا جاتا ہے۔ ایسے الفاظ کو اصطلاح میں متروک الفاظ کہتے ہیں۔ الفاظ کا متروک قرار پانا ایک طویل امر ہے۔ آغاز میں جو الفاظ شعراء اور ادباء ترک کرتے ہیں عوام انہیں استعمال کرتے رہتے ہیں البتہ ایک مدت کے بعد معاشرہ خود بخود ان الفاظ سے غیرمانوس ہوتا چلا جاتا ہے۔
اسی طرح اس اصلاح کے ذریعہ بعض رجحانات کا قلع قمع کیا جاتا ہے۔ یہ رجحانات عموماً معاشرہ پر منفی رنگ میں اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً اردو میں اصلاح زبان کی تحریک کا سبب ایہام گوئی کو قرار دیا جاتا ہے۔ ایہام عربی زبان کا لفظ ہے یعنی وہم میں ڈالنا۔ اصطلاح میں ایہام گوئی سے مراد یہ ہے کہ شعر میں ایسا لفظ لایا جائے جس کے دو معنے ہوں، ایک معنی اس مقام کے قریب ہوں اور دوسرے بعید لیکن شاعر معنی بعید مراد لے۔ مومن کا یہ شعر ایہام گوئی کی عمدہ مثال ہے: ؎
شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن
رات کاٹی خدا خدا کر کے
غرض اسی طرح بعض الفاظ و تراکیب اور رجحانات کو وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھال کر اپنانے یا رد کر دینے کا نام اصلاح زبان ہے۔ اردو زبان سے منسلک ادباء کو جب یہ احساس ہوا کہ اب یہ زبان اس حد بلوغت تک پہنچ گئی ہے کہ اسے اعلیٰ تخلیقی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس وقت ان کے پیش نظر تین اسالیب تھے: (1) غزل کا دکنی اسلوب (2) نستعلیق فارسی کا طرز (3) دہلی کے گلی کوچوں کی زبان۔ زبان کو فصاحت عطا کرنے کے لیے فارسی کا نستعلیق طرز یقیناً فطری انتخاب تھا۔ ایہام گوئی سے اکتائے اس وقت کے اردو شعراء نے آخر رد عمل کے طور پر زبان میں فصاحت پیدا کرنے کے لیے فارسی طرز کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ ڈاکٹر جمیل جالبی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں:
اس تحریک کے شعراء نے احساس، جذبہ اور خیال کو اپنی شاعری میں ایک ایسی شکل دی کہ نئے شعراء نے اس روایت کو اپنا کر اسے مکمل کر دیا۔ ردعمل کی تحریک نے تخلیقی سطح پر فارسی اثرات کو عام بول چال کی زبان میں جذب کر کے ایک ایسی صورت دے دی جس سے اردو زبان کے خدوخال متعین ہوگئے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اردو نے شعوری طور پر ہندی زبان کے اثرات اور الفاظ کو خارج کیا، یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ایک زبان بولی کی سطح سے ادبی سطح پر آتی ہے تو وہ اس غالب زبان سے دل کھول کر استفادہ کرتی ہے جس کی جگہ وہ لینے والی ہے۔ چوسر کے زمانہ میں انگریزی زبان کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا تھا اور اس نے بھی غالب فرانسیسی زبان سے نہ صرف دل کھول کر استفادہ کیا تھا بلکہ اس کی روح کو، اس کے اسالیب و اصناف کو پورے طور پر اپنایا تھا۔ اس دور میں یہی صورت فارسی زبان و ادب کی تھی۔ برصغیر کی کوئی زبان اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی کہ ایک نئی ابھرتی ہوئی زبان اس سے استفادہ کر سکے۔
(تاریخ ادب اردو جلد دوم ، مصنفہ ڈاکٹر جمیل جالبی، مجلس ترقی ادب، لاہور1982ء 354ص)
سب سے پہلے ایہام گوئی کو ترک کر کے ذہنی اور قلبی کیفیات کو مجاز اور حقیقت کے روپ میں ادا کر کے صحت مند رویوں کی پرورش کرنے کا سہرا حضرت مرزا مظہر جان جاناں کے سر جاتا ہے کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اس تحریک کی بنیاد رکھی بلکہ اپنے شاگردوں کو بھی اس بات پر اکسایا کہ وہ اس صحت مند اسلوب کی پیروی کریں۔ آپ نے طرز سخن کو سنوارنے کے لیے فارسی زبان کے کم و بیش پانچ سو شعراء کے ایسے کلام کا انتخاب کیا جس میں قلبی کیفیات اور عشقیہ جذبات کا اظہار حقیقت بیانی اور سادہ گوئی کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر انور سدید میرزا مظہر جان جاناں کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:
اصلاح زبان کی تحریک میں میرزا مظہر جان جاناں کو اولیت حاصل ہے۔ انہوں نے فارسی اور اردو زبان کو ایک ہی تار سے بننے کی کوشش کی اور اصلاح زبان کو مذہبی اور سیاسی فریضہ سمجھ کر انجام دیا۔
(اردو ادب کی تحریکیں، مصنفہ ڈاکٹر انور سدید، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی، اشاعت ششم، 2007ء، ص203)
میرزا جان جاناں کی خدمات کا اعتراف اپنی جگہ مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ آج آپ کا بہت تھوڑا کلام دستیاب ہے کہ جو گنتی کے چند اردو اشعار پر مبنی ہے۔ ترک ایہام میں جس مرد میدان کو درحقیقت رفعت اور سربلندی حاصل ہوئی وہ شیخ ظہور الدین حاتم ہیں۔ حاتم اپنے دور کے مقبول اساتذہ میں گردانے جاتے تھے۔ شاگردوں کی طویل فہرست میں مرزا رفیع سودا جیسے عظیم المرتبت قادر الکلام شاعر کا نام بھی شامل ہے۔ زمانہ کی رو میں ابتداء ً آپ نے بھی ایہام پر ہی طبع آزمائی کی لیکن بعدازاں اس کام سے ایسے بد دل ہوئے کہ آج صاف گوئی کی اصطلاح کے موجد کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ؎
ان دنوں سب کو ہوا ہے صاف گوئی کا تلاش
نام کو چرچا نہیں حاتم کہیں ایہام کا
ڈاکٹر سلیم اختر ،حاتم کے عہد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:
حاتم کو معاصرین کے مقابلہ میں کہیں پہلے، اصلاح زبان کی ضرورت اور اہمیت اور ایہام کے نقصانات کا احساس ہو گیا تھا۔ 1140ھ سے قبل پہلا دیوان اور 1160ھ میں دوسرا دیوان مکمل کیا۔ 57سال کی پختہ عمر میں بہت کہہ چکنے کے بعد انہوں نے اردو شاعری کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا واحد کام کیا جس کی نظیر صرف غالب کے ہاں ملتی ہے یعنی اپنے کلام میں سے کمزور اشعار خارج کر کے منتخب اشعار پر مبنی انتخاب مرتب کیا۔ بقول ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار: حاتم نے 1168ھ (عہد عزیزالدین عالمگیر ثانی) میں دیوان زادہ کی ترتیب کا بیڑا اٹھایا۔ دیوان قدیم سے غزلیات کا انتخاب کیا۔ زبان و بیان میں بہت سی تبدیلیاں کیں اور مذاق جدید کی غزلیات کو اس میں شامل کر کے نومرتبہ مجموعہ کا نام دیوان زادہ رکھا۔
خود شاہ حاتم نے بھی دیوان زادہ کا دیباچہ لکھ کر ان رجحانات اور تغیرات کے بارہ میں اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا ہے۔ تنقیدی، تحقیقی، لسانی اعتبار سے یہ نثری دیباچہ بھی حاتم کی تصنیفات میں بہت اہم ہے۔ دیوان زادہ کی تدوین 1169ھ میں مکمل ہوئی۔ حاتم نے خود بھی ایہام ترک کیا اور شاگردوں کو بھی باز رکھا۔ یوں معاصر شاعرانہ رویہ میں تبدیلی لانے کا باعث بنے۔
(اردو زبان کی مختصر ترین تاریخ، مصنفہ ڈاکٹر سلیم اختر، سنگ میل پبلیکیشنز، لاہور، 2008ء، ص 153)
ناسخ کے دور میں اصلاح زبان کا پس منظر
ایہام گوئی کے نقصانات اپنی جگہ مگر اس رجحان کے باعث الفاظ کے نئے مفاہیم پیدا کرنے اور لفظوں کو اچھی طرح ٹٹولنے کا عمل ضرور پروان چڑھا۔ مزید یہ کہ اس دلچسپ صنعت کے باعث لوگوں میں فارسی کے بالمقابل اردو شاعری کا ذوق فروغ پانے لگا۔ دہلی میں اصلاح زبان کی ہونے والی تمام تحریکیں درحقیقت دکن کے اس اسلوب کے خلاف رد عمل کے طور پر تھیں کہ جو ولیؔ کے ذریعہ دہلی آیا تھا۔
جب دہلی کے حالات دگرگوں ہوئے تو میر، سودا، میر اثر اور میر حسن جیسے نامی گرامی ماہرین فن دہلی کو خیرآباد کہہ کر لکھنؤ چلے آئے۔ یہ شعراء کا وہ گروہ ہے جو مزاجاً دہلی کا تھا اور مجبوراً لکھنؤ میں آباد ہوا۔ یہ تمام مستند شعراء تھے لیکن لکھنؤ میں سرکاری سرپرستی سے ہمیشہ محروم رہے۔ پھر لکھنؤ میں اودھ کی زبان کا لہجہ شامل تھاجبکہ دہلی میں میرٹھی اور مقامی زبانوں کا اثر تھا۔ان تمام باتوں کا اثر یہ ہوا کہ لکھنؤ کے شعراء میں دہلویت کے خلاف ایک تحریک نے جنم لیا اور ناسخ اس تحریک کے مرکزی کردار ٹھہرے۔ اسی طرح اس زمانہ میں ایک نئی طرز سخن ریختی نے بھی راہ پالی تھی۔ ریختی لکھنؤ کے مصنوعی معاشرہ کی مقبول لیکن غزل کی مبتذل صنف سخن تھی کہ جس میں عورتوں کی زبان میں محاورے، اشارے کنائے اور بیشتر جنس کے متعلق فحش اشعار کہے جاتے تھے۔ گو کہ ناسخ خود بھی اس صنف میں مشاق تھے لیکن بعد ازاں آپ ان شعراء میں شامل ہوئے کہ جنہو ں نے اس صنف سے بے اعتنائی اختیار کی۔ ڈاکٹر انور سدید ریختی کے ذیل میں کہتے ہیں:
یہ ایسی شاعری تھی جس میں لکھنوی معاشرہ کا سارا ابتذال سمٹ کر سما گیا تھا۔ چنانچہ عورتوں کے احساسات اور جذبات کو پیش کرنے کی بجائے رقیق اور سوقیانہ اظہار سے جنسی جذبات کو برانگیختہ کیا جانے لگا۔ رنگین اور انشاء نے اس صنف سے حکمرانوں اور رئیسوں کے سفلہ جذبات کی تسکین کی۔ لیکن میر، سودا، آتش، اور ناسخ جیسے شعراء نے اس صنف سے بے اعتنائی اختیار کی۔ چنانچہ اب یہ صنف سعادت یار خان رنگین اور جان صاحب کی ادنیٰ خیالی کی یادگار ہے۔
(اردو ادب کی مختصر تاریخ، مصنفہ ڈاکٹر انور سدید، عزیز بکڈپو، لاہور، طبع پنجم، 2006ء، ص 184)
اصلاح زبان میں ناسخ کا کردار
اصلاح زبان کی کوششوں میں ناسخ کو غیر معمولی مقام حاصل ہے اور اپنے اس کارنامہ کے باعث ناسخ کا نام اردو ادب میں ہمیشہ باقی رہے گا۔ لکھنؤ کا دبستان شاعری میں ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے صاحب جلوہ خضر کے حوالہ سے ایک طویل فہرست ایسے الفاظ کی شائع کی ہے کہ جو ناسخ کی اصلاح کی بدولت آج اردو زبان میں رائج ہے۔ مثلاً:
لفظ وقت سودا۔ میر، تبدیلی وقت ناسخ، پھرے ہے، پھرتا ہے، رنگ جھمکے ہے، رنگ جھلکتا ہے، آگو، آگے، کرے ہے، کرتا ہے، راہ گھیروں، راہ روکوں، کسو، کسی، بدلہ کرنا، بدلہ لینا، ان نے، اس نے، جگ، دنیا، ٹُک، ذرا
اس جیسے بیشمار الفاظ ایسے ہیں جو مصحفی، انشاء، میر حسن و دیگر کے وقت میں کسی اور صورت میں رائج تھے۔ مگر ناسخ نے ان کو تبدیل کر ڈالا۔ ناسخ سے قبل شعراء کے کلام میں ضرورت اور وزن کے خیال سے الفاظ کو تبدیل کرنا روا رکھا جاتا رہا مخفف کو مشدد اور مشدد کو مخفف استعمال کیا جاتا رہا۔ لفظ ثقیل اور غیر ثقیل دونوں کا استعمال قائم رہا۔ متروک الفاظ کا استعمال حتی کہ خود متروک قرار دیئے گئے الفاظ تک کو شعراء ضرورت پڑنے پر استعمال کرتے رہے۔ ابواللیث صدیقی کہتے ہیں:
غرض ان اصحاب (ناسخ کے پیش رو۔ ناقل) نے نہ کوئی اصول وضع کئے اور نہ اس کی پابندی کی ان کے برخلاف ناسخ نے فصاحت کے تین معیار متعین کر دیئے۔ تنافر نہ ہو، غرابت نہ ہو، تعقید نہ ہو۔ اس عام اصول کے بعد ناسخ نے یہ لازمی قرار دیا کہ لغات صحت کے ساتھ استعمال کئے جائیں، غیر زبان کے حروف دبنے نہ پائیں۔ ہندی زبان کے حروف دب سکتے ہیں مگر کم، قافیہ کے اصول سارے برتے جائیں، بندش چست ہو، حشو و زوائد کا دخل نہ ہو، ذم اور ابتذال کا پہلو شعر میں نہ نکلے۔
(لکھنؤ کا دبستان شاعری، مصنفہ ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی، اردو اکیڈمی، کراچی، طبع ثانی، 1967ء، ص246)
اصلاح زبان کی کوششوں کے ذیل میں آج ہم ناسخ کی سعی کا درست رنگ میں ادراک حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ اس بارہ میں ناسخ کی کوئی کتاب موجود نہیں اور نہ ہی ناسخ نے حاتم کی طرح کسی دیوان کے دیباچہ یا مقدمہ ہی میں اپنی ان شعوری کوششوں کا ذکر کیا ہے۔ اصلاح زبان کے باب میں ناسخ کے کردار کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں یہ بات مدنظر رکھنی چاہئے کہ ناسخ آسمان لکھنؤ پر بدر منیر کی سی حیثیت رکھتے تھے کہ جس کے اردگرد باصلاحیت شاگردوں کا جھرمٹ لگا رہتا تھا۔ پس آپ کی اصلاحات کے اثرات نہایت سرعت کے ساتھ رونما ہوئے۔ پھر دہلی کی قدیم روایات کے بالمقابل اہل لکھنؤ اپنی تخلیقی کاوشوں اور فکر و فن کی سرگرمیوں میں کسی صورت دبنے کو تیار نہ تھے۔ چنانچہ ناسخ جیسا زرخیر دماغ سرزمین لکھنؤ کے لیے کسی بھی طرح نعمت سے کم نہ تھا۔ ڈاکٹر انور سدید ناسخ کے ان کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:
ناسخ نے اردو کی صرف اور نحو کو درست کیا۔ روزمرہ اور محاورات کی چھان پھٹک کی اور اس کے قاعدے مقرر کئے۔ تمام مستعمل الفاظ کی تذکیر و تأنیث کے اصول تراشے، افعال اور مصادر میں اہم تبدیلیاں کیں۔ عروض و قافیہ کے لحاظ سے وزن اور شعر کی درستگی پر زور دیا۔ ناسخ کے یہ سب اصول حکم اور ضابطہ کی حیثیت رکھتے تھے اور ان سے انحراف کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ لکھنؤ میں ناسخ کی زبان کسوٹی بن گئی۔ ناسخ نے ریختہ کو اردو زبان کا نام دیا اور محاورہ دہلی کے مقابلہ میں محاورہ لکھنؤ وضع کیا۔ پہلے غزل کو بھی ریختہ کہا جاتا تھا لیکن ناسخ نے صنف غزل کے لیے ریختہ کو متروک قرار دے دیا۔
ناسخ کی اصلاحی تحریک کا ایک اخلاقی پہلو بھی ہے۔ قدما کے ہاں ہجو میں فحش نگاری اور بدزبانی کا رجحان عام تھا اس قبیح روش نے آہستہ آہستہ غزل میں بھی راہ پالی۔ ناسخ نے فحش الفاظ کو غزل میں ممنوع قرار دیا۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ شعراء غزل کے ایک اہم موضوع، عشق سے شعوری انحراف برتنے لگے اور یوں زندگی کے دوسرے موضوعات کو بھی غزل میں راہ مل گئی۔ ناسخ کی ضابطہ پسندی کو بالعموم قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ تاہم غزل کے موضوعات کو وسعت دینے کا اقدام ایسا ہے جس کی تحسین ضروری ہے۔
(اردو ادب کی تحریکیں، مصنفہ ڈاکٹر انور سدید، انجمن ترقی اردو پاکستان، اشاعت ششم،2007ء، ص 214)
بہرحال ناسخ کی اصلاحی سرگرمیوں کی وجہ خواہ کچھ بھی رہی ہو لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس باب میں ناسخ کے کردار کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک زبان میں متروکات کے عمل کا تعلق ہے تو جس طرح نشوونما کی ایک خاص سیڑھی پر یہ عمل شروع ہوتا ہے اسی طرح جب زبان پیچیدہ تخلیقی مضامین و مفاہیم کو ادا کرنے کی بھرپور صلاحیت پیدا کر لیتی ہے تو پھر یہ عمل بالآخر رک جانا چاہئے کیونکہ زندہ زبان کو قواعد کے نام پر پابندسلاسل کر دینا کسی صورت بھی انصاف پسندی نہیں کہلا سکتی۔ پس اس مرحلہ پر پہنچ کر الفاظ کو متروک کرنے کا سبب اس کے علاوہ کچھ نہیں رہتا کہ بعض الفاظ عوام کو ثقیل محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ادب کے مطالعہ سے دوری زبان میں موجود خوبصورت اور شیریں الفاظ سے اجنبیت پیدا کر دیتی ہے۔
(حافظ نعمان احمد خان)