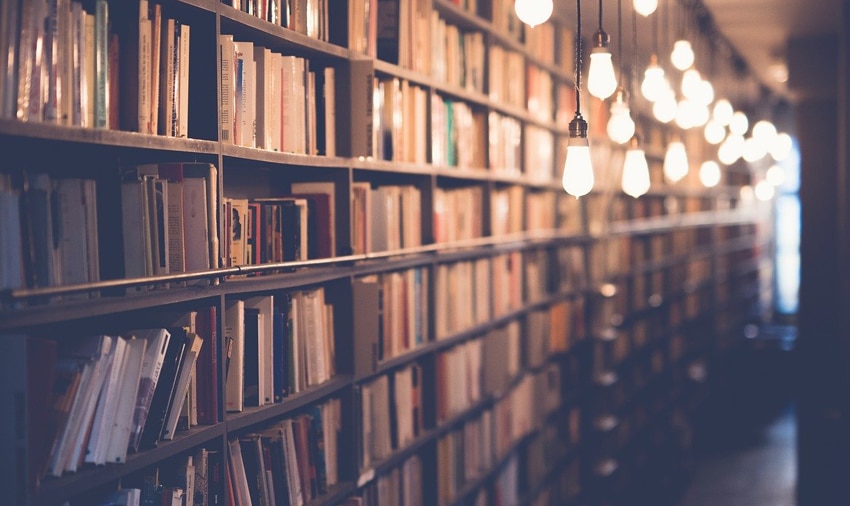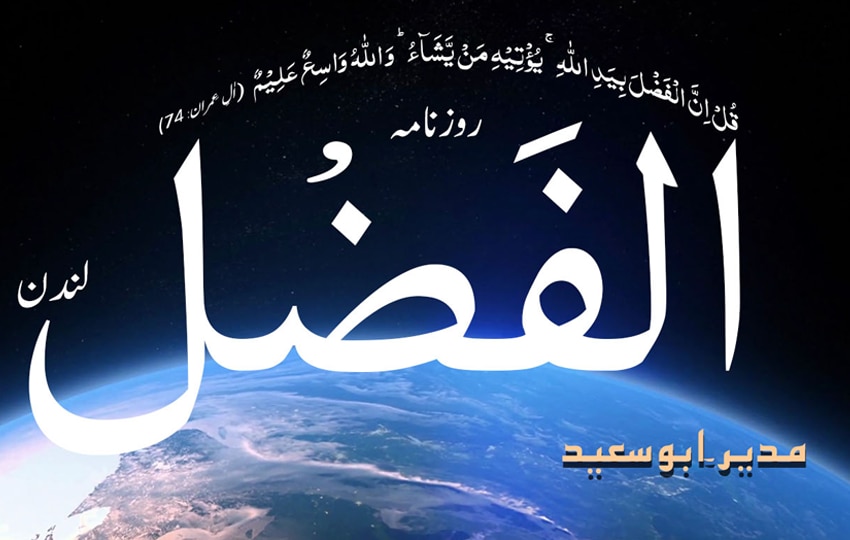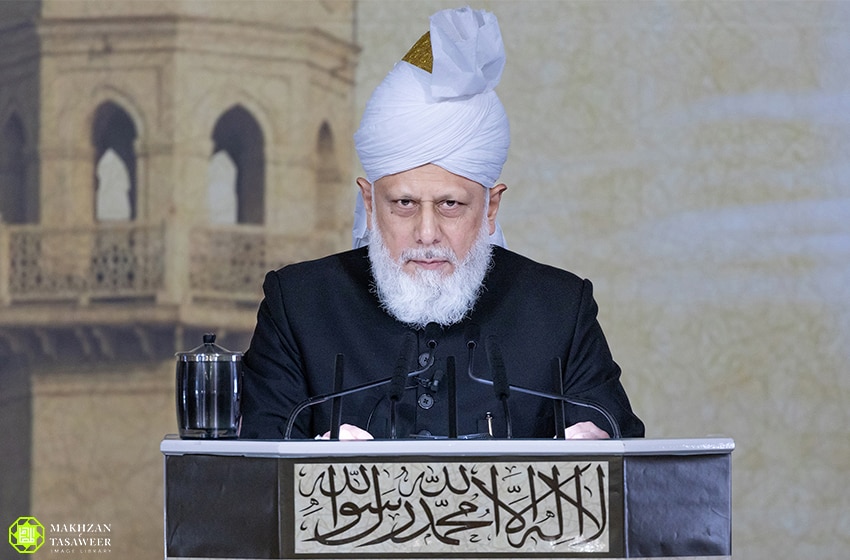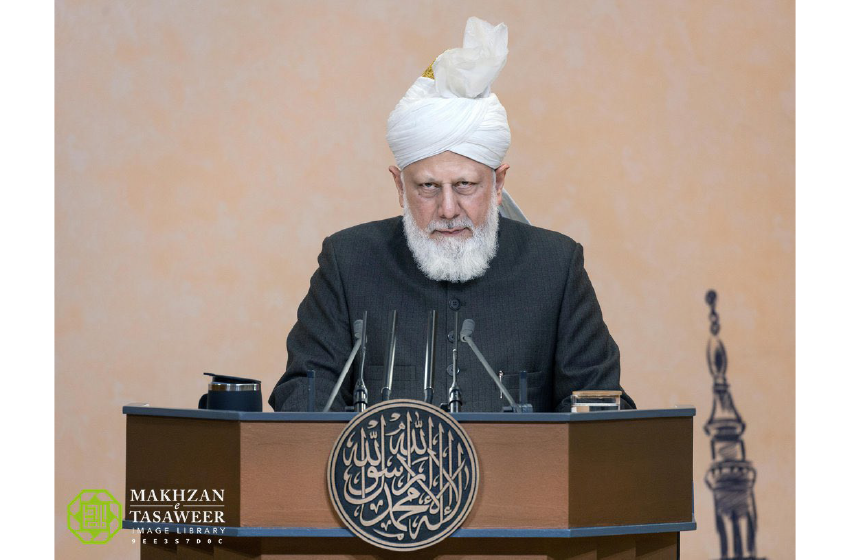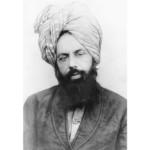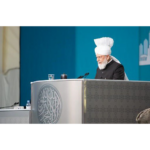یونانی فلسفے کے مسلمان مفکرین پر گہرے اثرات اور
نظریہٴ وحدت الوجود کا تدریجی ارتقاء
(قسط اول)
؎ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود
پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟
(غالب)
نظریہ وحدت الوجود حلول کی ایک بگڑی ہوئی یا ترقی یافتہ شکل ہے۔ حلول کا مطلب ہے دو اشیاء کا آپس میں اس طرح مدغم ہو جانا کہ کوئی فرق باقی نہ رہے۔ صوفیانہ اصطلاح میں روح خداوندی کا انسانی وجود میں سرایت کر جانا کہ ثنویت باقی نہ رہے حلول کہلاتا ہے۔ چونکہ یہ تصور اسلام کے نظریہء توحید سے کلی متصادم اور مخالف ہے اس لئے اسے مسلمانوں میں پذیرائی نہ مل سکی بلکہ اسے پوری شدت کے ساتھ ردّ کر دیا گیا۔ اس ماحول کے باوجود حضرت محی الدین ابن عربی نے اسے ایسی مغالطہ آفرینی اور پُر کشش اصطلاحات کے ساتھ پیش کیا کہ صوفیاء نے وحدت الوجود کو اسلام میں تصور توحید کی اصل شکل اور روح قرار دے کر قبول کر لیا۔ صدیوں سے اس پر بحث جاری ہے۔ اس موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی جاچکی ہیں اور اس کے متبعین آج بھی اسے اسلامی توحید کا مغز قرار دینے پر مصر ہیں۔ بنیادی طور پر وحدت الوجود کا تصور قدیم ہندو ویدانتی نظریے اور یونانی اور پھر فلاطینوسی نظریات سے اخذ شدہ ہے جسے اسلامی لباس پہنانے کی کوشش کی گئی۔
وحدت الوجود (Unity Of Existence) کا مطلب ہے وجود کا ایک ہونا۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ نے وحدت فی الوجود کی اصطلاح استعمال کی جسے بعد میں ان کے متبعین اور فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ کے شارحین نے وحدت الوجود کے نام سے بدل دیا اور اب یہ اسی اصطلاح سے معروف ہے۔ صوفیاء کے نزدیک اس کائنات میں حقیقی وجود صرف ایک ہے اور وہ خدا کا وجود ہے باقی سب وجود ظلی اور اعتباری ہیں۔ جس طرح انسان یا کسی مادی جسم کا سایہ ہوتا ہے جس کا اپنا ذاتی اور حقیقی وجود نہیں ہوتا بلکہ وہ اس وجود کا مرہون منت ہے جو اس سائے کی وجہ ہے۔ اسی طرح اس کائنات میں ہر چیز خدا کی وجہ سے قائم ہے اس کا اپنا علیحدہ کوئی وجود نہیں۔ اسی کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ یہ اتنا مشکل، گھمبیر اور نازک ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی لغزش ہو جائے تو اس کی سرحدیں واضح طور پر کفر اور شرک سے ملتی نظر آتی ہیں۔ اگر اس کی تشریح ہمہ اوست (سب کچھ خدا ہی ہے) سے کی جائے تو یہ Pantheism ہے جو کہ کھلا کفر اور شرک ہے۔ اس کے مقابل ہمہ از اوست (سب کچھ خدا کی طرف سے ہے) کی اصطلاح بھی بڑی مقبول ہے جسے وحدت الشہود کا نام دیا گیا ہے۔
حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کو اسلام میں مسئلہ وحدت الوجود کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ ابن عربی سے پہلے بھی بہت سے مسلمان مفکرین اور صوفیا بظاہر اس کے قائل رہے ہیں (مثلا منصور حلاج کا نعرہ انا الحق اور بایزید بسطامی کا قول سبحانی ما اعظم شانی) مگر جس وضاحت سے اور شرح و بسط سے ابن عربی نے اسے ایک باقاعدہ نظام کے طور پر متعارف کروایا اور اس کا پرچار کیا اس کی پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی۔ محی الدین ابن عربی کی ذات اس نظریے کی وجہ سے بڑی متنازعہ رہی ہے۔ ایک طرف انہیں کافر، ملحد، گمراہ اور مشرک تک کے القابات سے نوازا گیا تو دوسری طرف انہیں شیخ اکبر کا خطاب دیا گیا اور علماء اور صوفیا کا ایک جم غفیر ہے جو ان کے آستانے پر اپنا سر تعظیم و عقیدت سے جھکائے کھڑا ہے۔ دیو بندی، بریلوی اور اہل حدیث سبھی اس میخانے کے مے خوار نظر آتے ہیں۔ مسئلہ وحدت الوجود صوفیا کا پسندیدہ مسئلہ ہے اور صدیوں تک اس نے مسلمان اکابرین اور علماء و شیوخ کے ذہنوں پر راج کیا ہے۔ بدقسمتی سے اسے اسلام کی تعلیمات کا حصہ سمجھ لیا گیا اور صدیوں تک اس کے حق اور مخالفت میں بحثیں، مناظرے اور لڑائی جھگڑے ہوتے رہے ہیں۔ امام ابن تیمیہ اس کے شدید مخالفوں میں شامل تھے انہوں نے ابن عربی پر کفر کا فتوی لگایا اور شرعی زبان میں جو بڑی سے بڑی گالی ہو سکتی تھی وہ انہیں دی۔ دوسرا بڑا نام حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کا ہے جنہوں نے وحدت الوجود کے نظریے کو باطل قرار دے کر اس کے مقابل پر ہمہ از اوست کا نظریہ پیش کیا جسے وحدت الشہود کہا جاتا ہے۔ صرف صوفیاء اور علماء ہی اس کی زد میں نہیں آئے بلکہ اردو، عربی، فارسی اور پنجابی کے بے شمار شعراء پر بھی وحدت الوجود کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ وحدت الوجود کا رنگین نظریہ جب شاعروں کے ہتھے چڑھا تو انہوں نے وہ گل کھلائے کہ الحفیظ و الامان۔
مسئلہ وحدت الوجود کے بارہ میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ یہ کوئی ایمانی، اعتقادی یا شرعی مسئلہ نہیں بلکہ یہ صرف اور صرف ایک نظریہ ہے اور ایک فلسفہ ہے۔ بعض علماء اور مؤرخین اور شارحین تو اسے تصوف کا حصہ ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ بہر حال اس مسئلے نے مسلمان علماء اور صوفیاء اور شیوخ کو جس شدت سے اپنے حصار میں لیا ہے شائد کسی اور مسئلے نے اس شدت سے عوام و خواص کو اپنی گرفت میں نہیں لیا۔
؎ہم ہوئے تُم ہوئے کہ میر ہوئے
اُس کی زُلفوں کے سب اسیر ہوئے
اصل بات یہ ہے کہ نظریہ وحدت الوجود کا ہمہ اوست تصور ایک ایسی سرشاریت ہے کہ بقول علامہ اقبال جو ایک بار ابن عربی کے چنگل میں پھنس گیا اُس کا نکلنا محال ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو خدا کا جزو سمجھنے لگ جائے تو پھر اس مقام سے نیچے اترنا اس کے لئے ناممکن ہو جاتا ہے۔
اسلام کا تصور توحید
وحدت الوجود پر بات کرنے سے قبل یہ انتہائی ضروری ہے کہ توحید حقیقی کے اسلامی تصور کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا جائے تا کہ قاری کو یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہ رہے کہ نظریہ وحدت الوجود توحید کی حقیقی روح سے کس طرح متضاد اور مخالف ہے۔
1.خدا وحدہُ لا شریک ہے
قُلۡ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ ۚ﴿۲﴾ اَللّٰہُ الصَّمَدُ ۚ﴿۳﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙوَ لَمۡ یُوۡلَدۡۙ﴿۴﴾ وَ لَمۡ یَکُنۡ لَّہٗ کُفُوًا اَحَدٌ﴿۵﴾
(الاخلاص)
تُو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ بے احتیاج ہے۔ نہ اُس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ اور اُس کا کبھی کوئی ہمسر نہیں ہوا۔
2.معبود حقیقی صرف اللہ ہے
وَاِلٰـہُکُمۡ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ ۚ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ الرَّحۡمٰنُ الرَّحِیۡمُ
(البقرہ: 164)
اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ کوئی معبود نہیں مگر وہی رحمان (اور) رحیم ہے۔
ذٰلِکُمُ اللّٰہُ رَبُّکُمۡ ۚ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ۚ خَالِقُ کُلِّ شَیۡءٍ فَاعۡبُدُوۡہُ ۚ وَ ہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ وَّکِیۡلٌ
(الانعام: 103)
یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر چیز کا خالق ہے۔ پس اُسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔
3.خدا اس جہان کا خالق ہے
ہُوَ اللّٰہُ الۡخَالِقُ الۡبَارِئُ الۡمُصَوِّرُ لَہُ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰی ؕ
(الحشر: 25)
وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا۔ پیدائش کا آغاز کرنے والا اور مصور ہے۔ تمام خوبصورت نام اسی کے ہیں
الَّذِیۡ خَلَقَ الۡمَوۡتَ وَ الۡحَیٰوۃَ
(الملک: 3)
وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔
الَّذِیۡ خَلَقَ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا
(الملک: 4)
وہی ہے جس نے سات آسمانوں کو طبقہ در طبقہ پیدا کیا۔
اَلَمۡ تَرَ اَنَّ اللّٰہَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ بِالۡحَقِّ ؕ اِنۡ یَّشَاۡ یُذۡہِبۡکُمۡ وَ یَاۡتِ بِخَلۡقٍ جَدِیۡدٍ
(ابرھیم: 20)
کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ( اے انسانو!) تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے۔
4.خدا عدم سے پیدا کر سکتا ہے
اَوَ لَا یَذۡکُرُ الۡاِنۡسَانُ اَنَّا خَلَقۡنٰہُ مِنۡ قَبۡلُ وَ لَمۡ یَکُ شَیۡئًا
(مریم: 68)
تو کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اُسے پہلے بھی اس حال میں پیدا کیا تھا کہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔
وَّ قَدۡ خَلَقۡتُکَ مِنۡ قَبۡلُ وَ لَمۡ تَکُ شَیۡئًا
(مریم: 10)
اور یقینا میں تجھے بھی تو پہلے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کچھ چیز نہ تھا۔
بَدِیۡعُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ
(الانعام: 102)
ترجمہ: وہ آسمانوں اور زمین کا عدم سے پیدا کرنے والا ہے۔
5.خدا ہر چیز پر قادر ہے
اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ
(البقرہ: 21)
یقینا اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔
تَبٰرَکَ الَّذِیۡ بِیَدِہِ الۡمُلۡکُ ۫ وَہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرُ
(الملک: 2)
پس ایک وہی برکت والا ثابت ہوا جس کے قبضہء قدرت میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔
وَاِذَا قَضٰۤی اَمۡرًا فَاِنَّمَا یَقُوۡلُ لَہٗ کُنۡ فَیَکُوۡنُ
(البقرہ: 118)
اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اُسے محض ’’ہو جا‘‘ کہتا ہے تو وہ ہونے لگتا ہے اور ہو کر رہتا ہے۔
6.خدا بے مثل ہے
لَیۡسَ کَمِثۡلِہٖ شَیۡءٌ
(الشوری: 12)
اُس جیسا کوئی نہیں۔
7.خدا کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا
یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡہِمۡ وَمَا خَلۡفَہُمۡ وَلَا یُحِیۡطُوۡنَ بِہٖ عِلۡمًا
(طہٰ: 111)
وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے جبکہ وہ اس کا علم کے ذریعہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتے۔
8.ظاہری آنکھ سے خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا
لَا تُدۡرِکُہُ الۡاَبۡصَارُ ۫ وَہُوَ یُدۡرِکُ الۡاَبۡصَارَ ۚ وَہُوَ اللَّطِیۡفُ الۡخَبِیۡرُ
(الانعام: 104)
آنکھیں اس کو نہیں پا سکتیں ہاں وہ خود آنکھوں تک پہنچتا ہے اور وہ بہت باریک بین اور ہمیشہ باخبر رہنے والا ہے۔
9.خدا ربُ العلمین، رحمن، رحیم اور مالک یوم الدین ہے
اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ﴿۲﴾ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۙ﴿۳﴾ مٰلِکِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ؕ﴿۴﴾
(الفاتحہ: 2-4)
تمام حمد اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔
10.روح مخلوق ہے
وَیَسۡـَٔلُوۡنَکَ عَنِ الرُّوۡحِ ؕ قُلِ الرُّوۡحُ مِنۡ اَمۡرِ رَبِّیۡ وَمَاۤ اُوۡتِیۡتُمۡ مِّنَ الۡعِلۡمِ اِلَّا قَلِیۡلًا ﴿۸۶﴾
(بنی اسرائیل: 86)
اور وہ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تو کہ دے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں معمولی علم کے سوا کچھ نہیں دیا گیا۔
11.مادہ مخلوق ہے
خدا تعالی کی صفات علیم، مالک، قادر اور رحیم ثابت کرتی ہیں کہ مادہ مخلوق ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھیں ’’ہستی باری تعالی‘‘ از حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ صفحہ176 تا 181)
خلاصہ کلام یہ کہ خدا تعالی اپنی ذات اور صفات میں وحدہُ لاشریک ہے۔ کائنات خدا کی صفت خالقیت کی مظہر ہے۔ کائنات اپنے حقیقی وجود کے ساتھ خارج میں موجود ہے۔ خدا اپنی صفات کے ساتھ ازلی اور ابدی ہے۔ کائنات کا خدا تعالیٰ سے تعلق عینیت کا نہیں بلکہ غیریت کا ہے۔ خدا اپنی قدرت اور ارادے سے جب چاہے کوئی بھی شے عدم سے وجود میں لا سکتا ہے۔ خدا کی قدرت اور اس کا ارادہ اس کے علم کے تابع نہیں۔ مادہ خدا کی مخلوق ہے۔
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں:
’’خدا اپنی تمام خوبیوں کے لحاظ سے واحد لاشریک ہے۔ کوئی بھی اس میں نقص نہیں۔ وہ مجمع ہے تمام صفات کاملہ کا اور مظہر ہے تمام پاک قدرتوں کا اور مبدءہے تمام مخلوق کا اور سرچشمہ ہے تمام فیضوں کا اور مالک ہے تمام جزا سزا کا اور مرجع ہے تمام امور کا۔ اور نزدیک ہے باوجود دوری کے اور دور ہے باوجود نزدیکی کے۔ وہ سب سے اوپر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے کوئی اور بھی ہے۔ اور وہ سب چیزوں سے زیادہ پوشیدہ ہے مگر نہیں کہ سکتے کہ اس سے کوئی زیادہ ظاہر ہے۔ وہ زندہ ہے اپنی ذات سے اور ہر ایک چیز اس کے ساتھ زندہ ہے۔ وہ قائم ہے اپنی ذات سے اور ہر ایک چیز اس کے ساتھ قائم ہے۔ اُس نے ہر یک چیز کو اٹھا رکھا ہے اور کوئی چیز نہیں جس نے اُس کو اٹھا رکھا ہو۔ کوئی چیز نہیں جو اُس کے بغیر خود بخود پیدا ہوئی ہے یا اس کے بغیر خود بخود جی سکتی ہے۔ وہ ہر یک چیز پر محیط ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ کیسا احاطہ ہے۔ وہ آسمان اور زمین ہر چیز کا نور ہے اور ہر یک نور اسی کے ہاتھ سے چمکا اور اسی کی ذات کا پرتو ہے‘‘
(لیکچر لاہور روحانی خزائن جلد20)
اب فلسفہ یونان اور مسلمان فلاسفہ کو پڑھنے سے پہلے حضرت اقدس کا یہ ارشاد بھی پڑھ لیں:
’’یاد رکھو کہ انسان کی ہر گز یہ طاقت نہیں ہے کہ ان دقیق در دقیق خدا کے کاموں کو دریافت کر سکے بلکہ خدا کے کام عقل اور فہم اور قیاس سے برتر ہیں اور انسان کو صرف اپنے اس قدر علم پر مغرور نہیں ہونا چاہئے کہ اس کو کس حد تک سلسلہ علل و معلولات کا معلوم ہو گیا ہے کیونکہ انسان کا وہ علم نہایت ہی محدود ہے جیسا کہ سمندر میں سے کروڑم حصہ قطرہ کا۔ اور حق بات یہ ہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ خود ناپیدا کنار ہے ایسا ہی اس کے کام بھی ناپیدا کنار ہیں۔ اور اس کے ہر ایک کام کی اصلیت تک پہنچنا انسانی طاقت سے برتر اور بلند تر ہے۔‘‘
’’اگرچہ نادان فلاسفروں نے بہت ہی زور لگایا کہ زمین و آسمان کے اجرام واجسام کی پیدائش کو اپنے سائنس یعنی طبعی قواعد کے اندر داخل کر لیں اور ہر ایک پیدائش کے اسباب قائم کریں مگر سچ یہی ہے کہ وہ اس میں ناکام اور نامراد رہے ہیں اور جو کچھ ذخیرہ اپنی طبعی تحقیقات کا انہوں نے جمع کیا ہے وہ بالکل ناتمام اور نامکمل ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی اپنے خیالات پر قائم نہیں رہ سکے اور ہمیشہ ان کے خود تراشیدہ خیالات میں تغیر وتبدّل ہوتا رہا ہے اور معلوم نہیں کہ آگے کس قدر ہو گا۔‘‘
(چشمہٴ معرفت، روحانی خزائن جلد23، صفحہ280 تا 282)
مسئلہ وحدت الوجود کا پس منظر
وحدت الوجود کو سمجھنے کے لئے ہمیں تاریخی حقائق کے ساتھ جائزہ لینا ہوگا کہ اس کا اصل ماخذ کیا ہے اور اسلام میں اس کی در اندازی کیسے ہوئی۔ یہودیوں نے عزیر کو اور عیسائیوں نے مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیا، ہندؤوں میں اوتار کا تصور، شنکر اچاریہ کا ادوئیت کا فلسفہ، بدھ مت میں نروان کا حصول اور جین مت میں بت پرستی دراصل وحدت الوجود اور حلول ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ حلول سے مراد ہے ایک وجود کا دوسرے میں اس طرح سرایت کر جانا کہ کوئی فرق باقی نہ رہے۔ جیسے روح کا تعلق بدن کے ساتھ۔ وحدت الوجود کے مخالفین اور ناقدین اسے حلول ہی کی ایک شکل گردانتے ہیں۔ مگر وحدت الوجود کے حامی اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ حلول کے لئے دو وجودوں کا ہونا ضروری ہے جو ایک دوسرے میں مدغم ہو جائیں جبکہ شیخ اکبر کے فلسفہ وحدت الوجود کے مطابق کائنات میں خدا کے سوا کوئی دوسرا وجود موجود ہی نہیں۔ اور جب دوسرا وجود ہی نہیں تو حلول کیسے ممکن ہے؟ جو کچھ ہے وہ صرف ایک خیال ہے جس کا کوئی حقیقی وجود نہیں۔ اگر کائنات کو ایک حقیقی وجود مان لیا جائے تو ثنویت لازم آتی ہے اور یہ شرک ہے۔ (اس کی تفصیل ابن عربی کے باب میں آئے گی۔)
قرآن مجید حلول کے تصور کو کلیّتہ رد فرماتاہے۔ قرآن نے خدا اور انسان کی معیت اور قربت کی بات کی ہے جیسا کہ فرمایا:۔
وَ ہُوَ مَعَکُمۡ اَیۡنَ مَا کُنۡتُمۡ ؕ
(الحدید: 5)
اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔
اسی طرح سورة بقرہ میں ہے:۔
وَ اِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیۡ عَنِّیۡ فَاِنِّیۡ قَرِیۡبٌ ؕ
(البقرہ: 187)
اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں۔
تثلیث کے عقیدے کا ردّ سورت اخلاص میں اپنے انتہائی کمال درجے میں کر دیا گیا ہے۔ سورت توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَقَالَتِ الۡیَہُوۡدُ عُزَیۡرُ ۣابۡنُ اللّٰہِ وَقَالَتِ النَّصٰرَی الۡمَسِیۡحُ ابۡنُ اللّٰہِ ؕ ذٰلِکَ قَوۡلُہُمۡ بِاَفۡوَاہِہِمۡ
(التوبہ: 30)
اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصاری نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ محض ان کے منہ کی باتیں ہیں۔
ہندووٴں میں Pantheism کا تصور پایا جاتا ہے جو وحدت الوجود ہی کی تشریح ہمہ اوست کا دوسرا نام ہے۔ (بعض محققین کے مطابق ہمہ اوست کا نظریہ ہندووٴں میں ہزاروں سال سے موجود ہے اور ابن عربی نے وحدت الوجود کا تصور ہندو فلسفہ الہٰیات سے ہی حاصل کیا ہے)۔ اس کے مطابق کائنات میں موجود ہر چیز خدا کے وجود کا حصہ ہے اور اس بنا پر ہر شے الہامی ہے اور متبرک ہے۔ کرشنا، اوتار اور بھگوان سب ایک ہی ہیں۔ اسی نظریے کی بنیاد پر ہندو لاتعدا خداؤں کے بھی قائل ہیں اور ان کے بعض فرقے سورج، چاند، ستاروں اور آگ کے علاوہ درختوں، جانوروں، بتوں حتی کہ انسانوں کی بھی پرستش کرتے ہیں۔ ہندو فلسفہ اور طرز زندگی بھی عجیب ہے اس میں توحید بھی پائی جاتی ہے اور صریح شرک بھی موجود ہے۔ وحدت الوجود بھی ہے اور وحدت الشہود کے ماننے والے بھی ہیں۔ Monism سے لے کر Pluralism اور Pantheism تک ہر چیز ہندو فکرو فلسفہ میں پائی جاتی ہے۔
یونانی فلسفہ اور وحدت الوجود
قدیم یونانی فلسفے کو عموماً تین ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے:۔
i.پری سوکریٹیک فلسفہ:
800 -500 B.C.
(Pre Socratic Greek Philosophy)
ii.کلاسیکل یونانی فلسفہ:
500 – 323 B.C.
(Classical Greek Philosophy)
iii.ہیلینسٹک دور:
323 – 146 B.C.
(Hellenistic Period)
پہلا دور یونانی تاریک دور کے خاتمے یعنی آٹھ سو سال قبل مسیح سے لے کر پانچ سو سال قبل مسیح تک پھیلا ہوا ہے۔
دوسرا دور سقراط اور اس کے بعد (اسکندر اعظم کی وفات تک) کا عرصہ کلاسیکل یونانی فلسفے کا دور کہلاتا ہے۔
تیسرا دور اسکندر اعظم کی وفات سے لیکر روم کے یونان پر غلبے تک کا دور ہے۔ مگر یہ دور یہاں مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ رومن اور پھر اسلامی فلسفہ میں اپنے دیرپا اثرات کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔
سقراط سے پہلے کے فلسفہ دانوں میں جو نمایاں نام ہیں ان میں Thales, Heraclitus, Pythagoras اور Parmenides شامل ہیں۔ کلاسیکل یونانی فلسفے کو عہد زریں کہا جاتا ہے۔ اس دور میں سقراط، افلاطون اور ارسطو وہ نام ہیں جو بلاشبہ دنیائے فلسفہ کے استاد مانے جاتے ہیں جنہوں نے مغرب اور مشرق کے فلسفہ دانوں کو یکساں متاثر کیا۔ اسلام کی ابتدائی چھ صدیوں کے بڑے فلاسفر (الکندی، فارابی، ابن سینا اور ابن رُشد) افلاطون اور ارسطو کے نظریات کو آگے بڑھاتے رہے اگرچہ مسلمان فلسفہ نے یونانی فلسفہ میں اپنے مذہبی اعتقادات کو شامل کر کے اسے دنیائے اسلام کے لئے قابل قبول بنانے کی بھرپور کوشش کی۔
فلسفہ یونان میں فلاسفی کی قریباً ہر شاخ پر طبع آزمائی کی گئی مگر مابعد الطبیعات (Metaphysics) میں جن دو موضوعات کو بڑی تفصیل سے زیر بحث لایا گیا ان میں Ontology یعنی وجود کی بحث اور Cosmology یعنی کائنات کے اسرار و رموز جاننے کا علم شامل ہیں۔ یونانی فلاسفر ان بنیادی سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش میں سرگرداں رہے کہ وجود (Being) کیا ہے، اس کی تخلیق کب، کیسے اور کیوں ہوئی؟ اس تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ خالق کون ہے اور خالق و مخلوق کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ روح کیا ہے؟ جسم اور روح کا کیا تعلق ہے؟ موت کیا ہے؟ کیا موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ مادہ مخلوق ہے یا خدا کی طرح یہ بھی ازلی اور ابدی ہے وغیرہ۔ اس قسم کے لامتناہی سوالات ہیں جن کا جواب جاننے کی جستجو میں ہر دور کے فلسفہ دانوں نے اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق بڑی جدوجہد کی مگر یہ وہ سوالات ہیں جن کا حتمی جواب شائد فلسفہ کبھی نہ دے پائے گا۔
؎یہ غنیمت کہ اسرار ہستی سے ہم
بے خبر آئے ہیں بے خبر جائیں گے
کلاسیکل فلاسفی میں سب سے اہم سوال یہ رہا ہے کہ وجود کیا ہے اور Existence کیا ہے؟ جبکہ جدید فلسفہ میں Epistemology کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ علم کیا ہے؟ کثرت سے وحدت اور وحدت سے کثرت کا راز جاننے کی کوشش فلسفہ، مذہب اور سائنس میں ایک جیسی ہے۔
وجود کا مطلب ہے کسی چیز کا ہونا یا پایا جانا (الوجود شدن)۔ فلسفہ میں وجود کی بحث کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے:
1 – ناممکن الوجود: Impossible Being
2 – واجب الوجود: Possible Being
3 – ممکن الوجود: Contingent Being
ناممکن الوجود سے مراد ہے کوئی ایسا خیال جس کا وجود میں آنا ناممکن ہو مثلاً جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ عدم کا کوئی وجود نہیں اور یہ کبھی وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ واجب الوجود وہ ہے جو خود قائم ہو اور اسے اپنے وجود کے لئے کسی اور کی ضرورت نہ ہو۔ ممکن الوجود سے مراد وہ وجود ہے جو ممکن ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا اس کو وجود میں آنے کے لئے کسی اور واسطے کی ضرورت ہو۔ فلسفہ میں خدا کے لئے واجب الوجود (یا قدیم) اور مخلوقات کے لئے ممکن الوجود (یا حادث) کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ قدیم اور حادث کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ سوال انتہائی بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ ربط الحادث بالقدیم کی بحث ایک لامتناہی بحث ہے۔ (ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں والا معاملہ ہے)۔
یونانی فلسفے کا ذکر ہو اور عظیم معلم اخلاق، مفکر اور فلاسفر سقراط (Socrates) کا ذکر نہ آئے یہ ہو نہیں سکتا۔ اپنی سچائی اور حق پرستی کی وجہ سے ایتھنز کی عدالت سے سزائے موت پانے کے بعد زہر کا پیالہ پی کر ہمیشہ کے لئے امر ہو جانے والے سقراط کا کہنا تھا کہ روح کبھی نہیں مرتی اور جسم ایک فانی چیز ہے۔ انسان کوکبھی موت سے نہیں ڈرنا چاہئے۔ اگرچہ سقراط کی کوئی تحریر موجود نہیں مگر اس کی سوچ، فکر، فلسفے اور تعلیم کو اس کے شاگرد افلاطون (Plato) نے آگے بڑھایا۔ مکالمات افلاطون کا بیشتر حصہ سقراط کے فلسفہ پر مبنی ہے۔ افلاطون نے کائنات کی حقیقت اور کثرت سے وحدت کی تلاش میں بڑا کام کیا ہے۔
اس نے 36 کتابیں تحریر کیں۔ اس کا سارا کام آج تک محفوظ چلا آتا ہے۔ اس کی سب سے اہم اور شہرہ آفاق کتاب The Republic ہے جس کا ترجمہ جمہوریت اور بعض نے ریاست کے نام سے کیا ہے۔ افلاطون دنیا کے اُن افراد میں شامل ہے جنہوں نے انسانی ذہن پر اپنے فلسفے کے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اسے فلسفے کے طاقتور اور موٴثر ترین افراد میں شمار کیا جاتا ہے۔ افلاطون کے فلسفے کا ذکر کرنے سے پہلے ان چند یونانی فلاسفرز (سقراط کے علاوہ) کا ذکر کرنا ضروری ہے جن کی فکر اور فلسفہ افلاطون پر اثر انداز ہوا۔ ان میں Heraclitus, Parmenides اور Pythagoras (فیثا غورث ) کے نام نمایاں ہیں۔
ہیراکلیٹس کہتا تھا کہ ہر چیز ایک مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ کوئی چیز ساکن نہیں اور جو چیز ہر لمحہ تبدیل ہو رہی ہو اسے Define نہیں کیا جا سکتا مثلا ًآپ ایک منٹ پہلے جو تھے وہ اب نہیں ہیں اور جو اب ہیں وہ ایک منٹ کے بعد نہیں ہوں گے۔ یعنی ہر چیز ہے بھی اور نہیں بھی۔ چنانچہ جو چیز مستقل نہ ہو وہ حقیقت نہیں ہوتی اور اس کے بارہ میں ٹھوس علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس اصول کے تحت ہیراکلٹس نے کہا کہ کائنات غیر حقیقی اور Unreal ہے اور وہ جو حقیقت ہے وہ کہیں اور موجود ہے۔
پارمینڈیز (Parmenides) کو Metaphysics کا استاد مانا جاتا ہے۔ اس نے ہیراکلیٹس کے بالکل اُلٹ نظریہ پیش کیا اور کہا کہ اس کائنات میں کوئی چیز حرکت میں نہیں بلکہ جامد و ساکن ہے اور جو بھی حرکت ہمیں نظر آتی ہے وہ نظر کا دھوکا ہے سراب ہے Illusion ہے۔ پارمینیڈیز کا کہنا تھا کہ تبدیلی Being اور Non Being کے Interaction کے بغیر نہیں ہو سکتی اور چونکہ Non Being (عدم) کا کوئی وجود نہیں اس لئے تبدیلی ناممکن ہے۔ اس کے فلسفے کے مطابق:
Whatever Is, Is And What Is Not Can Not Be.
یعنی جو ہے وہ ہے اور جو نہیں ہے وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرے الفاظ میں عدم کا کوئی وجود سرے سے ہے ہی نہیں اس لئے عدم سے کوئی چیز وجود میں نہیں آسکتی، Out Of Nothing, Nothing Comesاپنے اس نظریے کی بنیاد پر پارمینیڈیز نے کائنات کو ازلی اور ابدی قرار دیا اور جس مادے سے یہ کائنات بنی ہے اسے یعنی وجود (Being) کو واحد آخری سچائی اور حقیقت کے طور پر پیش کیا۔ چنانچہ پارمینیڈیز نے ’’All Is One‘‘ کہہ کر وحدت الوجود کا ابتدائی نظریہ پیش کیا۔ پارمینڈیز نے پہلی دفعہ عقل (Reason) اور حواس (Senses) میں تفریق کی اور بتایا کہ علم صرف عقل کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حواس کے ذریعہ حاصل کردہ علم فریب نظر اور غیر حقیقی ہوتا ہے۔ چونکہ حواس غیر معتبر ہیں اس لئے مظاہر ایک دھوکا اور فریب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہندوستان میں اس مکتبہ فکر کا نمائندہ شنکر اچاریہ تھا جس نے تمام مظاہر فطرت کو مایا یعنی فریب نظر قرار دیا۔
اب آئیں Pythagoras (فیثا غورث) کی طرف جسے ریاضی کا عظیم ترین استاد مانا جاتا ہے۔ اس نے کائنات کی اصل ریاضی کے اعداد (Numbers) کو بنایا۔ فیثا غورث کا کہنا تھا کہ کائنات کی سچائی ریاضی کے اصولوں پر قائم ہے مثلا 2+2=4، کائنات میں جو مرضی تبدیلی ہوجائے دو جمع دو چار ہی رہیں گے۔ ریاضی کے اصول کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ وحدت سے کثرت کے بارہ میں اس کا نظریہ تھا کہ تمام اشیاء کی اصل واحد ہے۔ واحد سے اعداد نکلتے ہیں۔ عدد سے نقطے بنتے ہیں۔ نقطوں سے خط بنتا ہے، خط سے سطح بنتی ہے۔ سطح سے حجم بنتا ہے جس کی ایک صورت جسم بھی ہے۔ فیثا غورث روح کی ابدیت کا بھی قائل تھا۔
افلاطون کا نظریہ
(Plato’s Theory Of Forms)
جیسا کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ افلاطون فیثا غورث سے بہت متاثر تھا اور فیثا غورث کے نظریات کی بنیاد پر اس نے کائنات کی حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ اسی طرح سقراط، ہیراکلیٹس اور پارمینیڈیز کے نظریات سے بھی استفادہ کیا۔ افلاطون نے نظریہ پیش کیا کہ اس کائنات کے علاوہ بھی ایک کائنات ہے جو کہ اصلی، حقیقی، لازوال اور ابدی سچائی پر مشتمل ہے جبکہ یہ کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ غیر حقیقی، ہر لمحہ تبدیلی کے عمل سے گزرنے والی ہے اور اس کائنات کی کوئی بھی چیز آئیڈیل نہیں ہے۔ جبکہ اصل Reality کہیں اور موجود ہے۔ چنانچہ افلاطون نے کہا کہ اس کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز اپنی اصلی، حقیقی اور مثالی شکل میں اُس دوسری کائنات میں موجود ہے جو غیر مادی، غیر حسّی ہے اور Absolute ہے۔
اس غیر حسی کائنات کو اس نے عالم مثال کا نام دیا۔ جس طرح کسی چیز کا ایک سانچہ ہوتا ہے جو اصلی کہلاتا ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی لاتعداد کاپیاں بنائی جاسکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اینٹیں بنانے سے پہلے اس کا ایک سانچہ تیار کیا جاتا ہے اور پھر اسی سانچے کی شکل اور مقدار کی بنیاد پر بے شمار اینٹیں بنالی جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اس عالم حسی میں پائی جانے والی ہر چیز کا سانچہ غیر حسی اور غیر مادی دنیا میں موجود ہے جو مثالی ہے، اصلی ہے غیر مبدل ہے اور لازوال ہے۔ عالم حسی کے Objects عالم غیر حسی کی Imitations کے علاوہ کچھ نہیں اور یہ صرف علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہیں جن پر غور کر کے ہم حقیقت کا ادراک حاصل کر سکتے ہیں۔ افلاطون اپنے اس نظریے کی وضاحت اپنی کتابThe Republic میں ایک مثال کے ذریعہ کرتا ہے۔
غار کی مثال
Allegory Of A Cave
افلاطون ایک تصوراتی غار کا ذکر کرتا ہے جس میں کچھ لوگ غار کی اندرونی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں جن کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں اور وہ صرف سامنے والی دیوار کو ہی دیکھ سکتے ہیں۔ غار کے مُنہ سے روشنی سامنے والی دیوار پر پڑ رہی ہے اور جو کوئی شے غار کے مُنہ کے سامنے آتی ہے اُس کا سایہ سامنے والی دیوار پر پڑتا ہے۔ ان قیدیوں میں سے ایک شخص اپنی زنجیریں توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور غار سے باہر آ جاتا ہے۔ وہ رنگ برنگی چیزیں اور دوسرے انسان چرند پرند حیوان درخت وغیرہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ واپس غار میں جا کر قیدیوں کو اصل زندگی اور اصل دنیا سے آگاہ کرتا ہے مگر وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ افلاطون نے کہا کہ ہم لوگ اس دنیا میں غار کے اُن قیدیوں کی طرح ہیں جو عقیدوں اور رسم رواج کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور سایوں کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں جبکہ اصل حقیقت کچھ اور ہے اور اگر کوئی ہمیں اس سے آگاہ کرنے کی کوشش کرے تو ہم اسے پاگل اور باغی قرار دے کر سزا دیتے ہیں۔ اس مثال کے ذریعہ افلاطون نے اپنے استاد سقراط کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کو بھی تمثیلا بیان کر دیا۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی نے افلاطونی فلسفے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس دنیا کی ہر چیز کو غیر حقیقی، ظلی اور اعتباری قرار دیا اور افلاطون کے عالم مثال میں پائے جانے والے سانچوں (Ideas) کے مقابل پر اعیان ثابتہ کا تصور پیش کیا جس کی تفصیل میں ابن عربی کے ذکر میں بیان کروں گا۔
ارسطو کا نظریہ
(Aristotle Theory Of Forms)
افلاطون کا شاگرد اور اسکندر اعظم کا استاد ارسطو دنیائے سائنس اور فلسفہ کی وہ شخصیت ہے جس نے نہ صرف مغربی دنیا کے فلاسفروں کو بلکہ مذہبی رہنماؤں کو بھی اپنے سحر میں جکڑے رکھا۔ ارسطو کے نظریات کو عقیدے کی طرح مقدس سمجھا گیا اور اس کے مقابل پر اُٹھنے والی ہر آواز کو طاقت کے ذریعہ دبانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ خاص طور پر علم فلکیات اور زمین کے بارہ میں اس کے نظریات پر چرچ کوئی سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی شخصیت پرستی نے سولہویں صدی عیسوی تک سائنس کو آگے بڑھنے سے روکے رکھا تاوقتیکہ عظیم ریاضی دان نکولس کوپر نیکر نے ریاضی کے قطعی اصولوں کی بنیاد پر اس کے نظریات کو غلط ثابت کر کے دنیائے سائنس پر نئی سوچ اور ترقی کے دروازے کھول دئیے۔ Bruno, Galileo اور Newton نے علم فلکیات اور زمین کی ماہیت اور حرکت کو ثابت کر کے دنیا کو ارسطو کی شخصیت کے سحر سے آزادی دلائی۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ ارسطو عظمت کے جس مینار پر کھڑا ہے وہ عظمت وشہرت کسی اور کو نہ مل سکی۔
ارسطو نے افلاطون کے کسی غیر حسی دنیا اور اس میں پائی جانے والی Forms کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ مادی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہی اصلی اور حقیقی دنیا ہے یہ کوئی خواب، سراب، دھوکا یا Illusion ہرگز نہیں اور کسی مابعد الطبیعاتی دنیا کا کوئی وجود نہیں۔ ارسطو نے اپنے استاد افلاطون کے بارہ میں کہا ’’افلاطون بے شک میرا دوست ہے اور سچائی بھی میری دوست ہے۔ مگر سچائی میرے نزدیک زیادہ دوست ہے۔‘‘ اس طرح ارسطو نے افلاطون کو سر کے بل کھڑا کر دیا۔ ارسطو کا کہنا تھا کہ Forms اور Substance ایک دوسرے سے علیحدہ Exist نہیں کرتے بلکہ Substance کے اندر ہی اُس کی Form موجود ہوتی ہے جو مختلف اندرونی اور بیرونی تبدیلیوں اور اثرات سے گزر کر اپنی آخری شکل اختیار کرتی ہے۔ ارسطو کا کہنا تھا کہ ہر تبدیلی کے پیچھے ایک Cause موجود ہوتی ہے جو اس تبدیلی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور اس Cause کے پیچھے ایک اور Cause۔ اس طرح اگر اس سلسلہ کو Infinity تک لے جائیں تو ایک آخری ایسی قوت ملے گی جو ہر تبدیلی کی آخری اور Ultimate Cause ہے جو تمام سچائی کا منبع اور غیر متبدل ہے۔ ارسطو نے اسے Unmoved Mover کا نام دیا اور کہا کہ اسی طاقت کا نام خدا ہے۔ ارسطو کا کہنا تھا کہ وجود اور روح ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں اور جب کوئی وجود ختم ہوتا ہے تو اس کی روح بھی اس کے ساتھ ہی مر جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے۔
(جاری ہے)
(ڈاکٹر فضل الرحمن بشیر۔ موروگورو، تنزانیہ)